صفحات: 375
محاضرات ڈابھیل
فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا علمی حلقوں میں ایک معروف اور مستند نام ہے، فقہِ اسلامی اور فقہ المستجدات کے باب میں آپ ایک حوالے کا درجہ رکھتے ہیں، ستر سے زائد قرآن واحادیث، فقہ، سیرت، تاریخ، تذکرہ، سفرنامہ،تقابل ادیان اور فکری، اصلاحی اور تذکیری موضوعات پر عربی، اردو اور انگریزی کتابوں کے مصنف ہیں۔
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جہاں ایک بلند پایہ مصنف ہیں، وہیں آپ کو افہام وتفہیم حظ وافر عطا کیا گیا ہے، آپ کی گفتگو انتہائی مرتب ہوتی ہے، مولانا نے۱۶-۱۷ ذی قعدہ، ۸۳۴۱ھ کو جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل میں مختلف موضوعات پر قیمتی محاضرات دیے، ان محاضرات کو دار الحمد اسلامک ریسرچ اینڈ انسٹیوٹ نے عمدہ رنگین طباعت ، جابجا مناسب عنوان اور تحقیق و تعلیق کے ساتھ طبع کیا ہے۔
اس میں مختلف موضوعات پر دئے گیے کل آٹھ محاضرات ہیں:
(۱) مقاصدِ شریعت
اس کے تحت کل پانچ ذیلی عنوان ہیں، جنہیں مختلف نشستوں میں مکمل کیا گیا:
۱-مقاصدِ شریعت میں عہد بہ عہد ترقی کا تاریخی جائزہ۔
۲- مقاصدِ شریعت کے شرعی مآخذ۔
۳- مقاصد ِشریعت کی اہمیت۔
۴- مقاصد شریعت کا تعارف اور احکام شریعت کے مقاصد و مدارج۔
۵- مقاصد شریعت کے اعتبار کی شرطیں۔
(۲)فقہِ حنفی کی خصوصیات۔
(۳)فقہ حنفی کی عمومی خصوصیات۔
(۵)فقہ الاقلیات ۔
(۶) نقدِ حدیث میں علماءِ احناف کا منہج۔
(۷) درسِ قرآن و درسِ حدیث، چند گزارشات۔
(۸) درس ِقرآن کا طریقہ
ان خطبات و محاضرات کو دیکھ کر بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت فقیہ العصر نے فقہ ، اصولِ فقہ اور اصول حدیث کے اہم شعبوں اسی طرح ترویج قرآن و حدیث پر اپنی وسیع تر علمی خدمات و تجربات کی روشنی میں اہم ترین گوشوں پر گفتگو کی ہے۔
پہلا محاضرہ: مقاصد شریعت پر ہے، جس میں محاضر محترم نے مقاصد شریعت کے اَدوار، مآخذ، مقاصد شریعت کی اہمیت، تعارف اور اور اس کے اعتبار کی شرطوں پر گفتگو کی ہے۔
تاریخِ مقاصد شریعت کو چار اَدوار پر منقسم کیا: دورِ اول کا مصداق قرونِ ثلاثہ کو قرار دیا ہے،جس کے لیے کئی قرآنی استشہاد پیش فرمائے، دوسرے دور کا عرصہ قرون ثلاثہ کے بعد سے امام الحرمین تک کے زمانے کو قرار دیا، یہاں حضرت فقیہ العصر نے پانچ مصنفین (حکیم ترمذی، ابو منصور ماتریدی، ابوبکر قفال، ابوبکر ابہری اور ابوبکر باقلانی) کی مقاصد شریعت پر لکھی گئی مستقل تصانیف کا تعارف کروایا ہے، تیسرے دور کی تحدید امام الحرمین سے ابو اسحاق شاطبی تک کی ہے، اس دور میں اس موضوع پر لکھی گئی گیارہ مصنفین کی کتابیں شمار کروائی اور ان کا مختصرًا تعارف بیان فرمایا، اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت حکیم الامت تھانوی کی اس فن میں کیا خدمات رہی تفصیلا بیان فرمایا ہے، ضمنًا اس دور میں اس فن کی ترقی کی وجوہات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اسی طرح المعھد العالمی للفقہ الاسلامی (مصر) سے شائع ہونے والی کتبِ مقاصد شریعت پر چند نوٹ اپنی گفتگو میں شامل کئے ہیں۔
اس موضوع کا دوسرا حصہ: مقاصدِ شریعت کے مآخذ سے متعلق تھا، اس حصے میں مآخذ شریعت پر روشنی ڈالتے ہوئے شریعت کے احکام کا تکلیف سے تعلق یعنی حسن و قبح کی بحث میں اسلامی تراث میں مشہور تین نقطہائے نظر کی دل نشیں تشریح کی ہے۔ حضرت تھانوی کا مقولہ’’کسی بات کا ماورائے عقل ہونا الگ بات ہے اور خلاف ِعقل ہونا الگ بات ہے، اگر شریعت کی کوئی بات ہمیں سمجھ نہ آئے تو وہ خلاف عقل ہے ماورائے عقل نہیں‘‘ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ احکام شریعت میں مقاصد و مصالح کار فرما ہیں، اس پر قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے چند ایک دلیلیں پیش کی۔
اس کے بعد محاضر محترم نے مقاصد شریعت کی اہمیت و افادیت پر گفتگو کی، فقہ اسلامی میں مقاصد شریعت کا کیا رول رہا ہے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے، مقاصد شریعت کے ذریعہ نئے مسائل کی تحکیم اور مقاصد کی اہمیت کو ذکر کیا ہے، اس ضمن میں اجتہاد میں جن پانچ بنیادی عناصر کا ہونا ضروری ہے اسے تفصیلًا ذکر کیا ہے، اس کے بعد حضرت فقیہ العصر نے مدارجِ شریعت کا تعارف اور مختلف ادوار میں اس میں کمی بیشی کا ذکر کیا ہے، ہر ایک کے ایجابی و سلبی احکام کو ذکر کیا ہے، مقاصد شریعت میں تطبیقات کے لیے ان احکام کی درجہ بندی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں؛ ورنہ اس سے مفاسد کا باب وا ہونے کا خوف ہوتا ہے؛ اسی لیے اس کے ضمن میں ان مقاصد یا مدارج کی درجہ بندی ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کی تشریح، اور ان میں تطبیقات کے لیے بلو اور ریڈ لائن کی حدود کو متعین کیا ہے، اس موضوع پر آخری عنوان مقاصد شریعت کے اعتبار اور عدم اعتبار کے متعلق تھا، اس میں حضرت فقیہ العصر نے مقاصد شریعت کے ذریعہ اجتہاد و تحکیم کے باب میں تجدید کے عنوان سے مفاسد کے داعین پر تنقید کی ہیں۔اور اس کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے اصول و ضوابط پر روشنی ڈالی ہے۔
مقاصد شریعت پر معلومات سے بھر پور محاضرے کے بعد حضرت فقیہ العصر نے فقہ حنفی کی خصوصیات و اولیات پر شاندار گفتگو فرمائی، جس کے تحت فقہ حنفی کا اجمالی تعارف، احناف کے مجتہدات کی روشنی میں فقہ حنفی کی خصوصیات، اصول فقہ کے باب میں احناف کی خصوصیات و اولیات اور فقہ حنفی کے مراجع کا ذکر ہے، اسی کے تحت فقہ حنفی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے محاضر فرماتے ہیں کہ امام مالک کے شاگردوں میں ایک شاگرد اسد بن فرات تھے، انہوں نے امام مالک کے درس میں ایک مرتبہ کوئی سوال کیا، امام مالک نے جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا تو امام مالکؒ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جگہ نہیں، تمہیں کوفہ جانا چاہیے! یہ واقعہ فقہ حنفی کی اجتماعی تشکیل کو بیان کرتا ہے، کہ اس مجلس میں ہر ایک کی بات کو سنا جاتا تھا، اسے امامِ جلیل نے محسوس کیا اور ان کی اس طرف رہنمائی فرمائی، فقہ حنفی کی یہ اہم ترین خصوصیت ہے جو اسے دیگر مسالک سے ممتاز کرتی ہے۔
فقہ حنفی کے مصادر و مراجع کے جامع اور مختصر تعارف کے بعد فقہ حنفی کے مقام نشو و نما(کوفہ) اور وہاں رہنے والے لوگوں کی ذہنیت و ذہانت پر تبصرہ کیا، مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ سے منقول و مسموع ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک عباسی خلیفہ جب ماوراء النہر کے علاقے میں پہنچا تو بادشاہ کی آمد پر توپ نہیں داغی گئی تو خلیفہ نے وہاں کے گورنر سے پوچھا کہ توپ کیوں نہیں داغی گئی؟ گورنر نے جواب دیا کہ اس کی نو وجوہ ہیں: پہلی وجہ یہ ہے کہ بارود نہیں تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ باقی آٹھ کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بارود ہی نہیں تھا تو توپ کیسے داغی جاتی!
اس واقعہ سے اہلِ عراق کی خصوصی ذہنیت، تفکر اور دقیقہ رسی کو بیان کرنا مقصود ہے، اس کا اثر فقہ حنفی پر بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔
فقہ حنفی کی عمومی خصوصیات بیان کرتے ہوئے حریتِ شخصیہ، مذہبی رواداری، حلال وحرام کے احکام میں احتیاط، حسنِ اعتبار، عقل و نقل میں مطابقت، یسر وسہولت کا پہلو اور قانونِ تجارت میں دقتِ نظر وغیرہ مختلف خصوصیات کو مثالوں سے مبرھن فرمایا، وہیں فقہ تقدیری اور حیل کے ذریعہ فقہ حنفی پر اٹھائے جانے والے سوال کا تشفی بخش جواب دیا ہے، یوں یہ اہم ترین محاضرہ اے فائی سائز کے ۶۰ /صفحات کی ضخامت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔
تیسرا محاضرہ فقہ الاقلیات کے عنوان پر ہے، دنیا کی ہر قوم کی طرح مسلم قوم کو جب وطنیت کے بدبودار نظریے کے تحت تقسیم کیا گیا تو دیگر قوموں کی طرح مسلم قوم بھی اقلیت و اکثریت میں منقسم ہوگئی، مسلمان جب اقلیت میں ہو تو اس وقت کن معاییر کو بروئے کار لانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسے تفصیلا بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کا احترام اور قدر مشترک کی بنیاد پر کام کیا جاسکتا ہے، یہی اسلامی تعلیم کا نقطۂ نظر ہے، اس موضوع کی اہمیت اور موجودہ زمانے میں اس کی ضرورت سے اس محاضرہ کا آغاز ہوتا ہے، اس فقہ کے بانی کے طور پر مولانا نے شیخ یوسف القرضاوی کا نام شمار کروایا ہے، ان کی کتاب فقہ الاقلیات، فقہ الدولۃ اسی طرح فقہ الجھاد کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جزئیات سے کم اور اصول سے زیادہ بحث کی ہے، ان کتابوں کو فقہ الاقلیات کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں چوں کہ مسلمان اپنی ایک بڑی تعداد رکھنے کے باوجود اقلیت میں ہے، یہاں کے مسلمانوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں مثلا: سیاسی مسائل، سماجی مسائل، اور حکومت کے ساتھ مسلمانوں کا کیسا تعلقات ہونا چاہیے؟ اور حلقہ بگوش اسلام ہونے والے لوگوں کو در پیش مسائل کو اس محاضرے میں تفصیلا بیان کیا ہے اور ہر جزئیات پر حکم، حکم کا مدار اور اس کے پیچھے کارفرما اصول یا علت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، سیاسی مسائل کے تحت جیسے امیدوار بننا، ووٹ دینا، غیر مسلم پارٹیوں سے معاہدہ، رکن پارلیمنٹ بننا، دستور ہند پر حلف لینا اور جھنڈے کو سلامی دینا وغیرہ مسائل پر جامع مانع گفتگو کی گئی ہے۔
اسی طرح دسیوں سماجی مسائل کو بہترین اسلوب و انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
چوتھا محاضرہ نقدِ حدیث میں علماء ِاحناف کے معیار پر ہے، شروع محاضرے میں اس پر لکھی جانے والی دو کتابیں’’الأجوبۃ الفاضلۃ‘‘ اور’’الرفع والتکمیل‘‘ کا تعارف ہے، فقہاءِ حجاز اور فقہاءِ کوفہ کے اصول میں فرق کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا’’اصحاب الحدیث روایت کو باعتبار سند کے پہنچنے کی بنیاد پر قبول کرتے تھے، اور اصحاب الرائے درایتی نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے، یہ دونوں گروہ صحابہ کے دور میں بھی پائے جاتے تھے، احناف کے اصول حدیث میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ نقد حدیث کا کام صرف سند و درایت کے اعتبار سے نہیں ہوگا؛ بلکہ متن و درایت کے اعتبار سے بھی ہوگا۔‘‘(ملخصا)۔
اس کے بعداستنباطِ مسائل کے وقت احناف کے پیشِ نظر چند اصول حدیث پر گفتگو ہے، جو دیگر مذاہب کے اصولیین کے نزدیک قابل اعتناء نہیں سمجھے گئے، جیسے راوی کا تفقہ، صحت حدیث کے باوجود قابل عمل ہونے کے لیے عام قواعدِ شرع سے ہم آہنگی وغیرہ اصول کی بہترین تشریح ہے۔
پانچواں محاضرہ : درسِ قرآن و حدیث پر ہے، اس محاضرے میں بہ طور نمونہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر اور تفسیر کے وقت کن باتوں اور زاویوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اسے سہل انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسی طرح مشہور حدیث حدیث معاذ پڑھ کر سنائی، اور اس کے تحت جن فوائد کو بیان کیا جانا مناسب ہے، انہیں ذکر کیا ہے، اخیر میں امر المسلمین کی طرف پر سوز انداز میں نصوص کی روشنی میں توجہ دلاکر اس محاضرے کو مکمل کیا ہے۔
اس سلسلہ کا آخری محاضرہ درسِ قرآن کیوں اور کیسے ؟پر ہے، جس میں درس ِقرآن کو رائج کرنے کی ترغیب، اس کے اسلوب اور طریقہ کار پر ایک تفصیلی گفتگو ہے، اپنی تعلیمی، تدریسی اور تصنیفی زندگی کے بہت سے تجربات کی روشنی میں اس تخلیقی موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔
اخیر میں طلبہ جامعہ ڈابھیل سے خطاب ہے، جس میں حضرت فقیہ العصر نے تعلیم پر تحریض اور اس کی اہمیت پر گفتگو فرمائی ہے۔
کہا جاسکتا ہے کہ یہ محاضرات دریا بکوزہ کے مصداق ہیں۔
کتاب کا سرورق، طباعت اور اشاعت بہترین ہیں۔








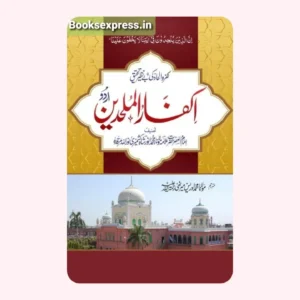
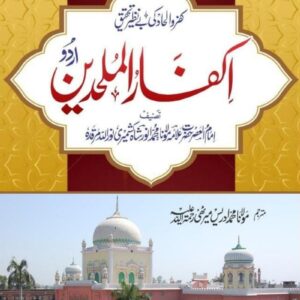

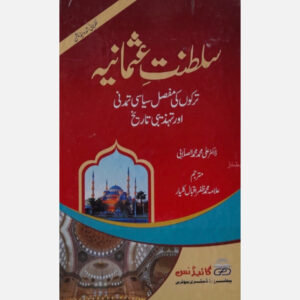
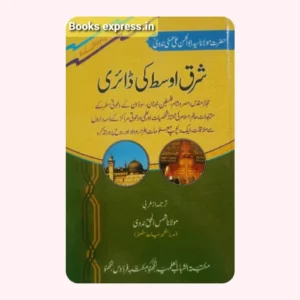


Reviews
There are no reviews yet.